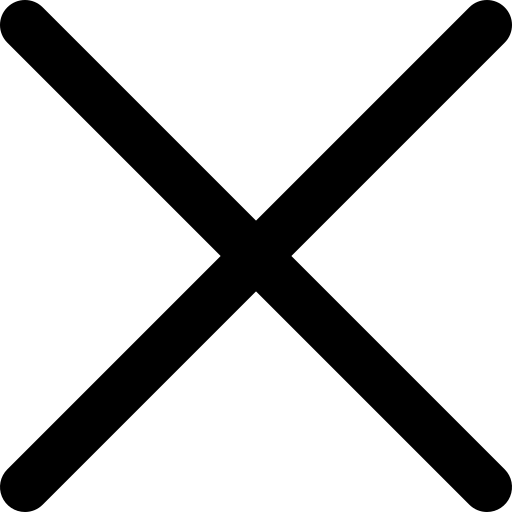محمد مدثر اشرفی
مدرسہ یا مکتب کا سیدھا مطلب ہے مکتب۔ اندرونی میی طور پر، اسے مذہب سے غیر جانبدار اور خصوصی طور پر تعلیم پر مرکوز ہونا چاہیے۔ جب سلطانی دور میں دہلی میں ایسا پہلا ادارہ قائم ہوا تو یہ ایک مثالی اسکول تھا جو سب کے لیے کھلا تھا۔صدیوں کے دوران، یہ مسلم مذہبی تعلیم کا گڑھ بن کر رہ گیا، اور وہ بھی صرف معاشرے کے نچلے طبقے کے لیے۔ سخت مذہبی مضامین تک محدود، مدارس بے کار ہو گئے اور آج مدرسہ کی جدید کاری کمیونٹی کی فکر اور حکومتی پروگرام دونوں ہے۔تاہم، مدارس کی جدید کاری کو اس کے تاریخی اور عصری دونوں طرح کے مجموعی تناظر کو سمجھے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔
8ویں سے 13ویں صدی تک اسلام کے پیروکاروں نے ثقافت، معیشت، تعلیم اور فکری ترقی کے میدان میں مثالی پیش رفت کی۔ انہوں نے نہ صرف مذہبی علوم کے اصول متعارف کروائے بلکہ ہمہ وقتی جدید مضامین جیسے طب، نظریات، ماہر لسانیات اور کثیر الضابطہ تحقیق کے اصول بھی مرتب کیے۔ یہاں تک کہ سنسکرت، فارسی اور یونانی زبانوں سے اور ان میں ترجمے بھی اس قدیم نفاست اور مہارت کے ساتھ کیے گئے تھے کہ اس نے علم اور اسکالرشپ کی ایک مضبوط بنیاد رکھی۔
بغداد کی بیت الحکمہ (علم و حکمت کے حصول کی اکیڈمی) دنیا بھر میں مشہور ہوئی اور تمام براعظموں کے طلباء کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ الخوارزمی (الجبرا کے بانی) اور ابن الہیثم (نظریات کے علمبردار) جیسے بے مثال مسلم علمی بزرگ مسلمانوں کے اس سنہری دور کے دستخط ہیں۔اسی دور میں مدارس یا مدارس قائم ہوئے۔ بنیادی طور پر مذہبی علم کو چینلائز کرنے اور مستحکم کرنے کے لیے، یہ مدارس بیت الحکمہ سے فکری سختی مستعار لیتے تھے جو کشادہ دلی اور آزادانہ فکری تحقیقات کے لیے وقف تھے۔
جیسا کہ عرب سرزمین کو منگول فوجوں نے تباہ کر دیا تھا، علماء کو وسطی ایشیا اور پھر ہندوستان میں محفوظ پناہ گاہ ملی۔ ہندوستان ہمیشہ علماء اور ہر قسم کی ثقافت اور مذہبی طریقوں کے لیے کھلا تھا۔ جلد ہی، مدارس – جو کہ مذہبی اور سائنسی تعلیم کے عرب اور ترک سلجوک ماڈلز کے ہائبرڈ تھے – نے ایک نیا ٹھکانہ اور ملک گیر طالب علم تلاش کر لیا۔سلطنت کے دور میں (پہلے سلطان، شہاب الدین محمد غوری، 1203-1206 کے زمانے سے)، مدارس مذہبی اور عدالتی افسران، بیوروکریٹس، اور یہاں تک کہ ریاضی اور سائنس جیسے دیگر شعبوں کے اسکالرز پیدا کرنے کی نرسری بن گئے۔ غوری نے اجمیر میں اسلامی ثقافت اور علم کو پھیلانے کے لیے ایک مدرسہ قائم کیا۔ تاریخی ماخذ "تاج المصیر" سے مراد محمد غوری کا اجمیر میں مدارس کا قیام ہے۔
بعد میں قطب الدین ایبک (1206-1210) اور سلطان التمش (1210-1236) نے دہلی، بدایون اور دیگر آس پاس کے علاقوں میں مساجد اور مدارس قائم کیے۔ سلطان ناصر الدین محمود (1246-1266) نے اس رفتار میں اضافہ کیا اور اس کے وزیر بلبن نے ان کے اعزاز میں مدرسہ ناصریہ کے نام سے ایک مشہور مدرسہ قائم کیا۔ علاؤالدین خلجی (1266-1287) کے لیے وقف ایک مدرسہ قائم کیا گیا اور دہلی میں مدرسہ مقبرہ علاؤالدین خلجی کے نام سے جانا جانے لگا، اور مدرسہ کے لیے پانی مہیا کرنے کے لیے قریب ہی ایک کنواں "حوز خاص" تعمیر کیا گیا۔

سلطان فیروز تغلق (1351-1388) نے تعلیم کے فروغ کے لیے اور بھی نمایاں کوششیں کیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے دربار میں ضیاء الدین برنی، مولانا جلال الدین رومی، قاضی عبدالقادر، اور عزیز الدین خالد خانی جیسے ممتاز دانشوروں کو اکٹھا کیا، جنہوں نے دینیات اور اسلامی فقہ پر کتابیں لکھیں۔ انہوں نے ملک بھر میں مدارس کی بنیاد رکھی۔
سکندر لودھی (1489-1517) خود ایک مشہور عالم تھے اور ان کی تعلیمی شراکت، بدقسمتی سے تاریخ کی ریت میں دفن ہے، اس قدر مثالی ہے کہ اس نے بعد کے دن جدید ترین اور اچھی طرح سے لیس مدارس کی بنیاد رکھی۔ ایک مشہور محدث عبدالحق نے کہا کہ سکندر لودھی نے مدارس میں تعلیم دینے کے لیے عرب، فارس اور وسطی ایشیا کے ماہرین تعلیم کو شامل کیا۔ اس نے متھرا اور آگرہ میں بھی مدرسے قائم کئے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ آگرہ کا مدرسہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں غیر مسلموں نے بھی فارسی زبان میں مہارت حاصل کی تھی۔ اس نے جونپور، احمد آباد، بہار شریف، گلبرگہ، بیدر، مند، دولت آباد اور بنگال کے کئی علاقوں میں مزید مدارس کی بنیاد رکھی۔ قابل ذکر اداروں میں سے ایک جونپور کا مدرسہ تھا۔ اسے عام طور پر "ہندوستان کا شیراز" کہا جاتا ہے۔
ان تمام اداروں نے، جس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، عقلی نصاب کی بنیاد پر ایک تعلیمی ماڈل تیار کیا۔ اسکولوں میں متنوع مضامین پڑھائے جاتے تھے جن میں منطق، ریاضی، فلکیات، کیمسٹری، طب، شاعری، تاریخ، جغرافیہ، قرآنی علوم، فقہ (فقہ) اور اسلامی قانون شامل ہیں۔ کچھ مدارس فنون اور دستکاری کی ہدایات اور سلطنت عثمانیہ کے مدارس اور یورپ کے اسکولوں کے ساتھ تبادلہ پروگرام کے لیے بھی مشہور تھے۔ان اداروں میں جو اس وقت ’’ایشیا‘‘ تھا اس کے آدھے سے طلبہ آتے تھے۔ان میں سے زیادہ تر مدارس کو مذہبی اوقاف سے تعاون حاصل تھا۔ انہیں مفت میں دی گئی زمینوں پر کرائے پر قائم کیا گیا تھا۔
19ویں صدی کے آخر تک ہر بڑے شہر میں موجود ہے۔ ان کا انتظام آخوند (پرنسپل)، مدارس (اساتذہ) اور متولی (مظلوم) کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ طلباء کو رہائش اور کھانا مفت دیا گیا۔ صرف اچھے طلباء نے ٹیوشن فیس ادا کی، اور غریب طلباء نے اسکول کے لیے کام کیا اور کالج کی خیراتی فاؤنڈیشن سے مالی امداد حاصل کی۔ ان مدارس نے ہندوستانی شہروں کو ریاضی، سائنس، طب، ثقافت اور معاشیات سے پروان چڑھایا۔یہ مدارس فقہ (قرآن، احادیث اور ان دونوں پر ابتدائی تفسیر)، اسلامی فقہ کی تفصیلات، 16ویں صدی تک جب مغل شہنشاہ اکبر نے فلسفہ اور منطق اور دیگر "عقلی مضامین" (مقولات) کو متعارف کرایا، پر توجہ مرکوز کی۔
اس وقت تک، مدرسہ کا ادارہ بتدریج جدیدیت سے گزر رہا تھا اور ایک خاص علاقے میں علم کے تمام مروجہ دھاروں سے ہم آہنگ ہو رہا تھا – جیسا کہ ہندوستان میں، وہ مذہب اور علوم تک پہنچنے اور سکھانے کے جنوبی ہندوستانی طریقے کو اپنا رہے تھے۔ شمالی ہندوستان میں، یہ ایک شمالی ہندوستانی نقطہ نظر تھا۔تاہم، جمود بھی قائم ہوا کیونکہ مغلوں کے زوال پذیر اور انتظامیہ ڈھیلی پڑ گئی، اور بعض اوقات شاہی امداد بھی خشک ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ، بدعنوانی عروج پر پہنچ گئی، مولویوں نے سیکھنے کے ان مراکز کو عطیات جمع کرنے کے مرکز میں تبدیل کر دیا، زیادہ تر ذاتی فائدے کے لیے۔ یہ تمام ادارے، جنہوں نے کبھی دنیا کے روشن ترین لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ مغرب میں روشن خیالی کے دور میں ہلچل مچا دی، اندھیرے میں اتر گئے۔ وہ اب صرف دینیات پڑھائیں گے۔
18ویں صدی میں، شاہ ولی اللہ اور ملا نظام الدین جیسے اصلاح پسندوں نے مدارس میں سائنسی تعلیم متعارف کرانے کی کوشش کی، لیکن معاشرے کے قدامت پسند عناصر کی مخالفت کی وجہ سے ناکام رہے۔
19ویں صدی کے وسط میں برطانوی راج کے قیام کے ساتھ ہی مقامی زبان اور مدرسہ کی تعلیم کو وجودی خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1832 میں فارسی کی جگہ انگریزی کو اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں خط و کتابت کی سرکاری زبان بنا دیا۔ قاضیوں اور علمائے کرام کو ریاست کی طرف سے تعینات کیا گیا تھا، ان کی جگہ برطانوی قانون میں تربیت یافتہ ججوں نے لے لی تھی۔ مسلم قانون کا اطلاق صرف ذاتی معاملات تک ہی محدود تھا، حالانکہ شریعت کو کسی مغل حکمران نے یا اس سے پہلے بھی مکمل طور پر متعارف نہیں کروایا تھا۔مدارس آہستہ آہستہ اپنی اہمیت کھوتے چلے گئے۔
بات حال کی
مدارس (یا مسلمانوں میں تعلیم) کی جدید کاری کا پہلا بڑا قدم مدرسۃ العلوم مسلمین ہند، یا محمد اینگلو اورینٹل کالج تھا، جس کی بنیاد 1875 میں سرسید احمد خان نے رکھی تھی جو کہ ہندوستانی مسلمانوں کے آج تک کے سب سے ممتاز تعلیمی مصلح ہیں۔ یہ 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کھلا اور اس نے مسلمانوں کے درمیان جدید، سائنسی اور انگریزی میڈیم کی تعلیم کو جنم دیا جو اس وقت سماجی جاگیرداری میں پھنسے ہوئے تھے اور الہیات پرستی میں پھنس گئے تھے۔تاہم معاشرے اور روایتی علمائے کرام کے دباؤ اور دباؤ نے یونیورسٹی کے اثر و رسوخ کو محدود رکھا۔ یہاں تک کہ اس نے کئی طریقوں سے معاشرے اور مدارس کی اصلاح میں مدد کی ہے۔
1986 تک اس وقت کی حکومت نے ان مدارس کے کام میں مداخلت نہیں کی۔ شاہ بانو کیس جیسے واقعات نے مدارس کے کام کرنے پر نئی روشنی ڈالی اور یہ کہ ان مدرسوں کے طلباء کی سوچ کے نمونے انہیں صرف چند اعلیٰ درجے کے مولویوں یا خود خدمت کرنے والے سیاست دانوں کے گلہ کرنے کے لیے موزوں رکھتے ہیں۔
مدارس کے سروے سے پتا چلا ہے کہ اکثر غریب خاندانوں کے لیے وہ واحد آپشن ہوتے ہیں، اور اردو، عربی اور قرآنی حفظ (حفظ) پر مرکوز فرسودہ نصاب کی وجہ سے مجبور ہیں۔ سائنس، ریاضی، انگریزی، اور تکنیکی مہارتوں کے لیے محدود نمائش روزگار کی صلاحیت کو روکتی ہے۔ 2006 تک، صرف 9.39% پرائمری اسکول کے بچے مدرسوں میں پڑھتے تھے، جن میں سے 90% سے زیادہ کا تعلق کم آمدنی والے گھرانوں سے تھا۔ زیادہ تر طلباء مالی دباؤ کی وجہ سے اپنی 20 کی دہائی کے اوائل میں تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، معمولی ملازمتوں کے لیے کیرالہ، جے پور، یا جودھ پور جیسے شہروں میں ہجرت کرتے ہیں۔
مختلف سروے ایجنسیوں کے اندازوں کے مطابق، 2025 تک، مدارس میں جانے والے مسلم بچوں کی تعداد تقریباً 4 فیصد، یا اس سے کم ہونی چاہیے۔
1986 میں، ہندوستان نے سائنس، ریاضی اور زبانوں کو روایتی نصاب میں ضم کرنے کے لیے مدرسہ کی جدید کاری کی اسکیم کا آغاز کیا۔ تاہم، قدامت پسند دھڑوں کی مزاحمت اور حکومتی حد سے تجاوز کے شکوک نے پیش رفت میں رکاوٹ ڈالی۔
1993 میں، ہندوستانی حکومت نے مدارس کو جدید بنانے کی ضرورت کو تسلیم کیا، اور وزیر اعظم پی وی نرسمہا راؤ کی انتظامیہ نے بابری مسجد کے انہدام کے بعد ملک کی دوسری سب سے بڑی اقلیت میں تحفظ کے احساس کو فروغ دینے کی کوشش کی، جس نے ہندوستان کے متعدد خطوں میں فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دی۔
2002 کے ایک میمو میں یہ لازمی قرار دیا گیا تھا کہ ریاست کی مالی اعانت سے چلنے والے مدارس اسٹیک ہولڈرز کو مزید پولرائز کرنے والی "ملک دشمن سرگرمیوں" سے باز رہیں۔
مزید برآں، قومی کمیٹی برائے اقلیتی تعلیم 2004 میں اس بات کا جائزہ لینے کے لیے قائم کی گئی تھی کہ مختلف ریاستوں میں مدارس کے حالات کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ 2009 کے بعد، مرکزی حکومت نے کئی پروگرام شروع کیے، جن میں مدرسہ اسکیموں کی جدید کاری(MOMS) اور کوالٹی ای فراہم کرنے کی اسکیم شامل ہیں۔
مدارس میں تعلیم(SPQEM)، جس کا مقصد ان تعلیمی اداروں میں زیادہ عقلی مضامین کو شامل کرنا ہے۔
2018 میں، وزیر اعظم نریندر مودی نے "قرآن اور کمپیوٹر" کے ساتھ مسلم نوجوانوں کو بااختیار بنانے پر زور دیا، حالانکہ ٹھوس نتائج بہت کم ہیں۔ کچھ ریاستوں نے مدارس کو غیر تسلیم کیا ہے یا اسلامی مضامین کو چھین لیا ہے، جس سے ثقافتی مٹانے پر بحث چھڑ گئی ہے۔
جامعات رضا بریلی، الجامعۃ الاشرفیہ (اعظم گڑھ) اور ندوۃ العلماء (لکھنؤ) جیسے ممتاز ادارے اب دینی تعلیم کو جدید تعلیمی مضامین کے ساتھ مربوط کرتے ہیں۔ اس کے برعکس، چھوٹے آزاد مدارس (آزاد مدارس)، خاص طور پر وہ جو دیہی علاقوں میں واقع ہیں، وسائل کی دستیابی سے متعلق چیلنجوں کا سامنا کرتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف جدید مضامین کو شامل کرنا ناکافی ہے۔ کامیابی کے لیے تربیت یافتہ اساتذہ، اپ ڈیٹ شدہ تدریس، فنڈنگ، اور کمیونٹی بائ ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جدت کے ساتھ روایت کا توازن حکومتوں، مدرسہ بورڈز اور سول سوسائٹی کے درمیان تعاون کا تقاضا کرتا ہے۔ بات چیت اور آگاہی کے ذریعے رجعتی ذہنیت پر قابو پانا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔
ہندوستان کے مدارس کی جدید کاری ایک طویل المدتی کوشش کی نمائندگی کرتی ہے جس کے لیے پالیسی سازوں، معلمین اور مقامی کمیونٹیز کے درمیان تعاون کی ضرورت ہے۔ روایتی طور پر، اسلامی تعلیم روحانی اور سیکولر علم کو مربوط کرتی ہے، ایک ایسا فریم ورک جو احیاء کے لائق ہے۔ معاشی ناہمواریوں سے نمٹنے اور نصابی خلا کو پر کرنے سے، مدارس ایسے جامع اداروں میں تبدیل ہو سکتے ہیں جو اپنی ثقافتی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے پسماندہ مسلمانوں کو بااختیار بناتے ہیں۔ جامع پالیسیوں اور کمیونٹی کی حمایت کے ذریعے، یہ مراکز روایت کو جدیدیت سے جوڑ سکتے ہیں، تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں اپنی اہمیت کو یقینی بنا سکتے ہیں۔
اقلیتی امور کی وزارت کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق، ہندوستان میں 24,010 مدارس ہیں، جن میں سے 4,878 غیر تسلیم شدہ تھے، 2018-19 میں۔ ان کے پاس، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے، تقریباً 4 فیصد یا اس سے کم مسلم بچے، جن کی عمریں 7-19 سال ہیں، ان کی فہرست میں شامل ہیں۔ قومی تعلیمی پالیسی 2020 نے معاشرے کے پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے تعلیم کو آزاد کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مدارس ایسی پالیسی کی تشکیل کا مرکز ہیں۔
اکیسویں صدی میں، دنیا بھر میں مدارس کے زیادہ تر اسکولوں نے سائنسی نصاب کو اپنا لیا ہے، جس نے ان کے طلباء کی ملازمت میں اضافہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر، سنگاپور میں مدرسہ کے نظام نے جدید ٹیکنالوجی جیسے ٹیبلیٹ کو شامل کرنا شروع کر دیا ہے اور یہاں تک کہ مصنوعی ذہانت کے کورسز کو بھی شامل کیا ہے تاکہ طلباء کو وقت کے ساتھ تازہ ترین رکھا جا سکے۔ہندوستان کو مدارس کو جدید بنانے کے لیے ایسا ہی یا اس سے بہتر ماڈل تیار کرنا ہوگا۔
(مصنف مدرسہ سے فارغ التحصیل، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ریسرچ اسکالر اور ایم ایس او کے قومی صدر ہیں)